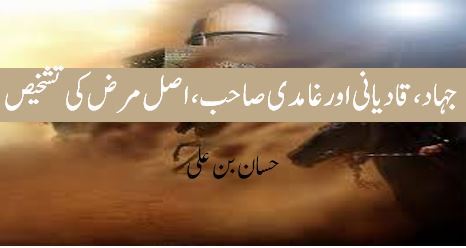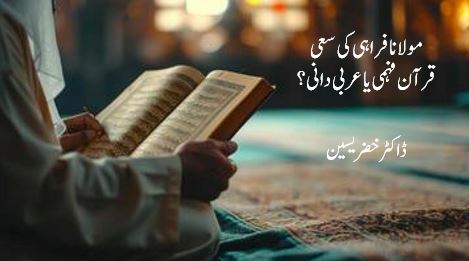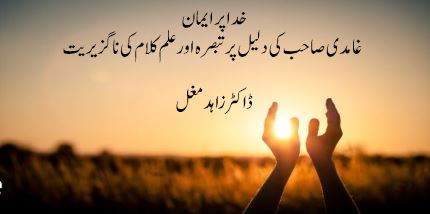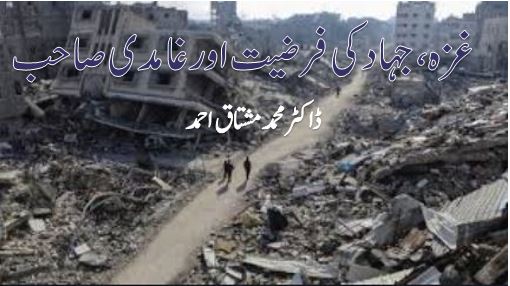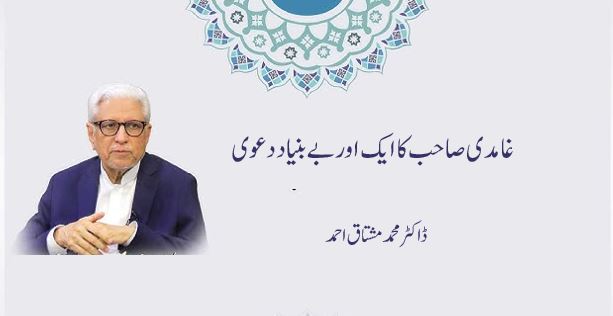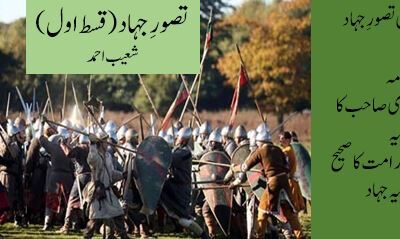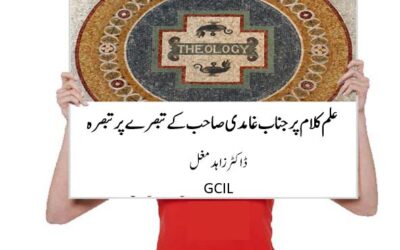ڈاکٹر زاہد مغل
ایک ویڈیو میں محترم غامدی صاحب علم کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے ایک حرف غلط قرار دے کر غیر مفید و لایعنی علم کہتے ہیں۔ اس کے لئے ان کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ فلسفے کی دنیا میں افکار کے تین ادوار گزرے ہیں:۔
– پہلا دور وہ تھا جب وجود کو بنیادی حیثیت دی گئی اور تخیل کے زور پر وجودی افکار وضع کئے گئے جن کا حقیقت سے کچھ لینا دینا نہیں۔ خدا کی ذات و صفات کی کلامی بحثیں اسی فکر کی بازگشت ہیں
– دوسرا دور علمیات کی بالادستی کا آیا اور یہاں وہ جدیدیت اور نام لئے بغیر کانٹ وغیرہ کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اس فکر کی کوکھ سے سائنس و تجرباتی علم نے جنم لیا جس کی ایک مضبوط بنیاد حسی علم کی صورت موجود ہوتی ہے جبکہ پہلے قدم کا فلسفہ نرا تخیل ہے
– تیسرا دور وہ ہے جب انسان کی آزادی کو بنیادی محور بنا لیا گیا، یہاں وہ پس جدیدی افکار کی جانب اشارہ کرتے ہیں
علم کلام کو پہلے دور سے متعلق تخیلاتی علم قرار دیتے ہوئے انہوں نے اسے بالکل بے معنی و غیر ضروری قرار دیا، ان کا کہنا ہے کہ یونان سے آئے اس فلسفے کا جواب دینے اور اس کے تحت دینی عقائد کو بیان کرنے کے بجائے اسے اٹھا کر باہر بھینک دینا چاہئے تھا اور قرآن کے افکار پیش کرنا چاہئے تھے جو سادہ و فطری وغیرہ ہیں۔
ہماری رائے میں علم کلام پر یہ تبصرہ افسوس ناک بھی ہے اور اس علم کی روایت کی زیادہ شناسائی کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ فلسفیانہ افکار کی کلاسیفیکشن وغیرہ سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں یہاں اس بات پر بھی تبصرہ نہیں کرنا کہ وجودی فکر پر جو تبصرہ انہوں نے کیا وہ درست ہے یا غلط، حیرانی تو اس بات پر ہے کہ آخر متکلمین کے منہج کو یونانی و نیوافلاطونی وجودی فکر سے خلط ملط کرکے کیسے اس پر ایسا حکم لگایا جاسکتا ہے؟ یہ بات تو حقائق کے خلاف (فیکچوئیل ایرر) ہے۔ آخر اشاعرہ و ماتریدیہ نے نیوافلاطونیت کو کب قبول کیا؟ واقفین اسلامی فلسفہ و کلام جانتے ہیں کہ ان گروہوں نے اسے رد کیا اور اہل سنت کی عقیدے کی روایت کے مین سٹریم کلامی گروہ یہی ہیں۔ ان گروہوں نے افلاطون (م 347 ق م) کے عالم مثال کو ماننے کی ضرورت سے انکار کیا، اسی طرح “وجود کی وحدت” کے کلی نظام فکر کو بھی قبول نہیں کیا، اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے ارسطو (م 322 ق م) کے کلیات خمسہ اور وجود ذہنی کی روایت کو بھی پوری طرح قبول نہیں کیا۔ جدید اصطلاحات میں کہا جائے تو اشاعرہ و ماتریدیہ کا فریم ورک براہ راست حقیقت پسندی اور اسمیت پسندی (نامینل ازم ) سے قریب ہے۔ بعض مفکرین نے جن خیالات کا سہرا ولیم آف اوکھم (م 1347 ء) کے سر باندھ کر اسے جدیدیت و تجرباتی سائنسی علوم کی بنیاد رکھنے والا قرار دیا ہے، وہ افکار اس سے بہت قبل تفصیل سے متکلمین اسلام کے یہاں زیر بحث آچکے تھے، افکار کے تاریخی ارتقا سے متعلق یہ تجزئیے کچھ زیادہ بامعنی نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برصغیر کے بعض دیگر مفکرین کی طرح غامدی صاحب بھی نیو افلاطونیت ہی کو مسلمانوں کی علم کلام کی روایت سمجھنے کی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برصغیر میں عام طور پر نیوافلاطونی افکار سے نسبتاً قریب علامہ ابن سینا (م 1037 ء) اور شیخ اکبر (م 1238 ء) و ملاصدرہ (م 1640 ء) وغیرہ کی روایات مشہور رہی ہیں، حضرت مجدد الف ثانی (م 1624 ء) اور شاہ ولی الله (م 1762 ء) کا خانوادہ اسی فکر کا نمائندہ تھا۔ لیکن اسے ہی مسلمانوں کی عقیدے کی مین سٹریم علمی روایت فرض کرلینا اور علم کلام کے مواقف کو اس کے کھاتے میں ڈال دینا ناقابل فہم ہے اور اس بنیاد پر علم کلام کو فضول و لایعنی قرار دینا بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ مسند ارشاد پر بیٹھے حضرات کو اسلامی علوم سے متعلق لوگوں میں ایسی غلط فہمی پھیلانے سے گریز کرنا چاہئے۔